
گلزاراحمد،وجاہت علی عمرانی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
نیلے عنبرپربادل کے تیرتے سیاہ و سفید ٹکڑوں کے ساتھ ادھر اُدھر کے دلکش نظارے کرتے اور خاموشی سے چلتے ہوئے، عمرانی صاحب نے یکدم ماضی اور حسین نظاروں کی بجائے انہوں نے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ گلزار صاحب! ہمیں کیوں کر لکھنا چاہیے؟ لکھنا کیوں ضروری ہے؟ میں لکھوں، تو کیوں؟ ایک لمبی فہرست ہے جو ابھی لکھتی ہے۔ انہیں کوئی پڑھتا بھی ہے یا نہیں، میں نے لکھا تو کون پڑھے گا؟ آخر بڑے بڑے لکھاری موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں ہمارے لکھنے کا فائدہ؟۔ عمرانی صاحب کا سوال اوربات درست تھی۔ دماغ کے دریچے میں سوال سر اٹھاتا ہی ہے۔ بالکل عمرانی صاحب! حقیقت یہی ہے کہ لکھاریوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ وہ بھی لکھ رہے ہیں جنہیں صرف پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ادب میں بے ادبیاں طبع نازک پر گراں گزرتی ہیں پر کیا کیجیے کہ دانش گردیاں ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پر کی جاتیں ہیں۔ پوچھنے والا کون ہے؟۔
آسمان سے ہمکلام ہوتی ہوئی مختلف گلی، محلوں کی دیواروں کے سائے سائے چلتے چلتے اب ہم دھپاں والے بند” کی مرکزی سڑک پر آ نکلے۔ دریا کے کنارے آنے تک دھوپ مدہم ہو چلی تھی۔ سامنے شینھ دریا کا دلفریب نظارا آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ دریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عمرانی صاحب کہنے لگے۔۔ گلزار صاحب ”تبت ” والے کہتے ہیں کہ یہ دریا شیر کے منہ سے نکلتا ہے، اس لیے انہوں نے اسے شیر دریا کا نام دیا۔ اس میں کمال دریا کا نہیں اُس شیر کا ہے جس نے اپنے قبیلے کی روایت توڑ کر نعمت نِگلی نہیں اُگلی ہے۔ تنگ وادیوں میں شور مچاتا یہ سندھو دریا یہاں پہنچ کر اس طرح شانت ہو جاتا ہے جیسے تھک ہار کر جاڑے کی گلابی دھوپ میں لیٹا ہوا ہو۔
ہم سڑک پر خراماں خراماں چلتے ہوئے اور ماضی کی یادیں تازہ کرتے ہوئے آخر کار دریائے سندھ کے سڑک کنارے ” دلبر” کیفے کو چائے پینے کے لیئے چُن لیا ارادہ تو مڈوے تک جانے کا تھا، لیکن کیا کرتے بعض مسائل کی وجہ سے مفتی محمود آئی ہسپتال والی چوکی پہ موجود پہرہ داروں نے مڈوے تک جانے والے راستے کو مکمل طور پر بند کیا ہوا تھا۔ سو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے قدم دلبر کیفے پہ آ کے رُک گئے۔ چائے پیتے ہوئے ہم نے سامنے دور نگاہ دوڑائی۔ شیر دریا سکون سے، ٹھہر ٹھہر کر بہہ رہا تھا جیسے عمر ڈھلنے پر عورت پرسکون اور ٹھہری ٹھہری لگتی ہے۔ غروب ہوتے سورج کی زوال پذیر روپہلی کرنیں یوں آہستہ آہستہ دریا میں اُتر رہی تھیں جیسے کوئی دیوی اشنان کرنے کے لئے مقدس پانی میں پہلے آہستہ سے اپنے پیر کی انگلیاں ڈبوئے، پھر تِلوے اور آخر میں ایڑھیاں۔
قدرت اپنے حسین ترین روپ میں جلوہ گر تھی۔ چائے پینے کے بعد مشترکہ فیصلہ کیا کہ نیچے اتر کر بیٹ پر چہل قدمی کرتے ہوئے دریا کے پانی تک جانا چاہیے۔ سو وہاں سے نیچے اترے، درختوں کے گھیرے میں لمبی گھاس سے ڈھکا ایک قطعہ کو عبور کر کے ہم بیٹ کی چکنی مٹی اور ریت تک پہنچ گئے۔ دریا کنارے دور تک پھیلی ہوئی ریت جس پر ہوا کے ہاتھوں تراشی ہوئی لہریں تھیں جن پر نہ قدموں کے نشان نہ کسی پیروں کی چاپ۔ ریت کا ایسا کورا پنڈا دیکھ کر جی مچلنے لگا کہ اس پر دور تک ننگے پاؤں چلا جائے۔ حتی کہ عروضی زمانوں سے باہر نکل جائیں۔ مٹی اور ریت کے بنتے بگڑتے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے درمیان ریت کے چھلاوے رقصاں تھے سورج کی ہلکی سی تپش جوں کی توں برقرار تھی۔ مگر ریت کے پیالے تلے دم توڑتی قدروں کی کہانی سانس لے رہی تھی۔ وقت اور تہذیب کا سفر کبھی تھما نہیں۔ تھم جائے تو شاید متعفن ہو جائے۔ تہذیب کے ٹیلے بھی کبھی کھائیوں میں بدل جاتے ہیں اور کبھی کھائیاں ٹیلوں جتنی بلند ہو جاتی ہیں۔ قریب رہنے والے حتی کہ اپنا وجود بھی نگاہوں سے اوجھل اور دور بسنے والے رگ جاں سے بھی قریب ٹھہرتے ہیں۔
ہمارے دائیں طرف” آدی واسی” یعنی خانہ بدوشوں کیہلوں کی چند جھونپڑیاں تھیں جن کے آس پاس ان خانہ بدوشوں کے ننگ دھڑنگے بچے کھیل کود میں مصروف تھے۔ ان پھول سے بچوں کو دیکھ کر اس بات پر یقین ِ کامل ہو جاتا ہے کہ ان پھولوں جیسا رنگ وقت کے ساتھ ساتھ جلتے تانبے جیسا ہوجاتا ہے۔ دریا کنارے رہتے ہوئے بھی پیاس سے ہونٹ سوکھے پتے جیسے ہوجاتے اور گلے میں ریت اٹکنے لگتی ہے۔ نزدیک ہی ان چند بڑی عمر کے بچوں کی طرف میں نے اشارہ کیا جو دریا کی گیلی چکنی مٹی سے کھلونے بنانے میں مشغول تھے۔۔ عمرانی صاحب! ان کی طرف دیکھیں یہ بچے بچے فطرت کے خزانے سے اپنے طور اپنا تعلق استوار کر رہے ہیں۔ یاد ہے ہمارے دور میں بچے مٹی، پتھر، لکڑی، پانی، پھول اور پتوں میں کھیلتے بڑے ہو جاتے۔ اور ان کھلونوں سے لطف اندوز ہو لینے کے بعد ان کو تلف کرنا کوئی چیلنج نہ تھا۔ زمین فطرت کا یہ خزانہ بڑی فراخ دلی سے واپس اپنے دامن مین سمیٹ لیتی تھی۔ گزرے وقتوں میں بچے بے قیمت اشیاء کو خزانہ سمجھ کر عزیز رکھتے تھے۔ اب سامان کی اتنی کثرت کا نتیجہ یہ ہے کہ بیش قیمت کھلونے سے بھی کچھ دنوں کے بعد دل بھر جاتا ہے اور نئے کی خواہش مچلنے لگتی ہے۔یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ بچوں کو جدید کھلونوں کے نام پر چھوٹی عمر سے ہوس اور ذخیرہ اندوزی اور دکھاوے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ ان کی تخلیقی صلاحیت بھی پروان چڑھے، اور کرہ ارض کے نظام تنفس پر پلاسٹک کے انبار کابوجھ کچھ کم ہو۔مگر پھر بھی ایک خلش ہے کہ آج ہمارے بچے مٹی میں ہاتھ نہیں لتھڑ سکتے، پانی میں بھیگتے نہیں، پتوں اور لکڑی کے ٹکڑوں کو بڑی احتیاط سے چھوٹی صندوقچیوں میں جمع نہیں کرتے کہ ان کے پاس بیش قیمت کلیکشن ہوتے ہیں۔آج بچے سکرینوں پر نظریں جمائے رکھتے ہیں اور گلیوں میں گھوم کر ہماری طرح کچی مٹی اور انوکھے پتھر ڈھونڈنے نہیں جا سکتے۔ شاید اس لئے کہ گلیاں صاف ستھری ہیں، درخت کاٹے جا چکے، پتھر کوٹ کر بہتر اور ہموار سڑکیں بچھا دی گئی ہیں اور گلیوں محلوں میں اجنبی درندوں کی آبادیاں بڑھ گئی ہیں۔
(جاری ہے)

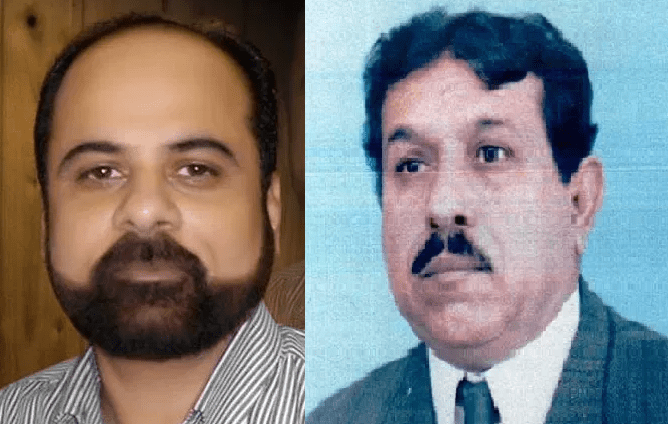

یہ بھی پڑھیے
””میاں عثمان عباسی کنوں نکھیڑے دِی ݙَنج“ (وسیب یاترا :9)||سعید خاور
”شیر دل رانی، مائی چھاگلی (وسیب یاترا :8)||سعید خاور
”چِڑیاں اُٹھو کوئی دھاں کرو“ (وسیب یاترا :7)||سعید خاور