
رسول بخش رئیس
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
توجوان تحریکِ انصاف کا ہراول دستہ تھے۔ ان کا عمران خان پر اندھا اعتماد تھا کہ خاندانی سیاسی جماعتوں سے امیدیں کھو بیٹھے تھے۔ ان کی کرپشن کے قصے کہانیاں‘ پسماندگی‘ معاشی جمود‘ سیاسی عدم استحکام اور بنتی بگڑتی حکومتوں کے کھیل سے دلبرداشتہ تھے۔ سیاست نئی نسل کے لیے لوٹ کھسوٹ کا دوسرا نام تھا۔ جب تک دو بڑوں کے مابین باریاں لگتی رہیں‘ وہ سیاست سے بیزار اور کوسوں دور رہے۔ سیاسی جماعتوں کے جھنڈے اٹھا کر نعرے لگانا تو درکنار وہ ووٹ بھی بہت کم تعداد میں ڈالنے لگے تھے۔ ویسے تو عوام بھی کسی حد تک غیر سیاسی ہو چکے تھے‘ مگر تعلیمی اداروں میں تو سیاست نام کی کوئی چیز ہی نہ رہی تھی۔ ملک کے معروضی حالات تبدیل بھی ہو چکے تھے۔ آزادیاں کم ہوتی جائیں‘ بندشیں بڑھتی جائیں تو نوجوانوں کی فکری نشوونما بھی متاثر ہوتی ہے۔ معاشرے اور افراد کی اندرونی دنیا مباحث‘ تنقید اور نظریاتی تنوع سے آباد رہتی ہے۔ جب سیاسی اور سماجی تحریکیں چلتی ہیں تو نوجوان طبقہ درسی کتابوں کے محدود دائروں سے نکل کر ان میں شامل ہوتا ہے‘ اور اپنی تلاش کے سفر میں کئی منزلیں بھی طے کر لیتا ہے۔ اگر ایک ہی چھاپ ہو اور سب کی تسلیم و رضا ہی مقصد ہو تو ذہن‘ سوچ اور فکری زاویے گہرے اور وسیع نہیں ہو پاتے۔ اس درویش نے تو ساری زندگی نوجوانوں کے درمیان گزاری ہے۔ اپنے دور کے ان پرانے وقتوں سے بہ آسانی موازنہ کر سکتا ہوں۔ وہ ساری دنیا میں نوجوانوں کی بغاوت کا زمانہ تھا۔ نظام‘ سماج‘ حکمران اور سب غالب نظریات کو چیلنج کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی نہیں‘ کچھ پڑھنے اور سمجھنے کے بعد۔ اساتذہ بھی ایسے ہوتے جو علم و ادب اور فلسفے کے میدانوں میں نام رکھتے تھے۔ فکری رہنمائی اور سوچ کی شمعیں روشن رکھنا ہی ان کی پہلی اور آخری دلچسپی تھی۔ وہ بھی تو آزادی کی تحریک کی پیداوار تھے۔ ان کے دل میں نئی پاکستانی نسل کی تعمیر تھی جس کے لیے وہ اپنا علم اور تجربہ بانٹتے‘ ہر نئے آنے والے طالب علم کو راستہ دکھاتے اور کئی اگلی منزلوں کی طرف روانہ کر دیتے۔
پہلے تیس سالوں کے بعد جو ملکی حالات پیدا ہوئے‘ داخلی سیاست جمہوریت چھوڑ کر اور راستوں پر چل نکلی تو سوچوں پہ پہرے حکمرانوں کی بقا کے لیے ایک ضرورت بن گئے۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صرف ریاستی یا کسی ایک جماعت اور گروہ کی طرف سے نہ تھا‘ بلکہ ہر کوئی اپنا نظریاتی ڈنڈا چلانا چاہتا تھا۔ ہم تو کئی ادوار کے عینی شاہد ہیں‘ جمہوریت کے لبادوں میں بھی فسطائیت دیکھی ہے۔
طلبا اور نئی نسل کو غیر سیاسی کرنے کا مقصد ایک ہی نظریاتی رنگ میں رنگنے کی کوشش تھی۔ غلط یا صحیح‘ اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہم بہت محدود حد تک اور ایک محدود مدت کے لیے ‘ بس پہلے تین عشروں تک عملی طور پر کثیر نظریاتی معاشرہ رہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک دوسرے کے نظریاتی جھنڈوں اور ڈنڈوں سے خوف آنے لگا کہ سروں پہ بھی تو پڑ رہے تھے۔ ارد گرد کے خطے میں بھی ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ ان کے نظاموں اور جنگوں نے یکطرفہ نظریوں کو مضبوط کیا تو تعلیمی اداروں میں ایک ہی رنگ کے جھنڈے لہراتے نظر آئے۔ ملک کے کونے کونے میں آزاد رو‘ آزاد خیال اور اپنا نظریہ اور دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے مختلف زاویہ ہائے نگاہ رکھنے والوں کو چن چن کر نکالا گیا۔ اور جو رہ گئے انہوں نے مجذوبوں کی سی خاموشی اختیار کر لی۔ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے لکھوں گا۔ ہم تو کمزور دل تھے۔ اتنے خوفزدہ کہ نظریات کو صرف پڑھانا ہی فریضہ سمجھا اور وہ بھی بہت احتیاط کے ساتھ کہ کہیں کوئی غلط لفظ منہ سے نہ نکل جائے۔ سب زور پیشہ وری پر لگا دیا‘ محفلیں محدود کر دیں۔ یوں سمجھئے دنیا سے کنارہ کش۔ جبر کی حکمرانیاں مشاہدے میں آنے کے بعد دو ہی تو راستے ہوتے ہیں‘ ٹکرائو یا دوڑ۔ ہم بزدل تھے‘ ٹکر لینے والے بہادر ہیں اور پھر معلمی کے پیشے کے اپنے آداب بھی تو ہوتے ہیں کہ عملی سیاست‘ کسی بھی نوعیت کی ہو‘ سے کوسوں دور رہنا ہے‘ لیکن مسئلہ تو اپنی جگہ رہتا ہے کہ علمِ سیاست پڑھائیں اور آپ غیر جانبدار ہوں؟ اپنے نظریات بیان کرنے اور رائے دینے میں منافقت سے کام نہیں لیا جا سکتا اور نہ ایسا کسی کو کرنا چاہئے۔ بات طریقے اور سلیقے سے کی جائے تو خطرات پیدا کرنے والے خود پسپا ہو جاتے ہیں۔
جمہوریت بحال بھی ہوئی تو جو اس کے گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے تھے اور جنہوں نے بہت سے گھڑ سوار ان کے قافلوں میں بطور حفاظت اور اعانت مہیا کیے تھے‘ ان کے لیے بھی محدود دائروں میں رہنا سیاسی ضرورت تھی۔ دریں اثنا تعلیمی اداروں میں لسانی‘ علاقائی اور فرقہ وارانہ تنظیموں نے نوجوانوں میں جگہ بنا لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ترقی پسند نظریات‘ مشرق و مغرب کے فلسفے‘ یہاں تک کہ ہمارے اپنے تہذیبی رنگ ماند پڑ گئے۔ ہم نے شام کے ڈھلتے ہوئے سورج کے خوبصورت شفق میں انہیں ڈوبتے دیکھا۔ کیا کرتے‘ اپنے اپنے گھروندوں میں ارد گرد روشنی رکھنے کے لیے چراغ جلا کر جانے والوں کی یادوں کے سہارے زندگیاں گزارتے رہے۔
معافی چاہتا ہوں‘ یہ یادیں کہاں سے کہاں درویش کو گھسیٹ کر لے گئیں۔ عمران خان سیاسی افق پہ ابھرے تو روایتی طور پر ”سنجیدہ‘‘ سیاسی لوگوں نے انہیں سنجیدہ نہ لیا۔ ابھی میدان سیاست میں قدم رکھا ہی تھا کہ آغا شاہی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ ان کے لیے اسلام آبادکونسل آف ورلڈ افیئرز کے اراکین کے ساتھ ایک خصوصی نشست کا انتظام کروں۔ میں اس تنظیم کا بانی سیکرٹری جنرل تھا۔ جب خان صاحب تشریف لائے تو ان کے ساتھ صرف محترمہ نسیم زہرا صاحبہ تھیں۔ ایسے لگا کہ وہ ابھی اپنا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ بہت عرصہ بعد دو ہزار پانچ اور سات میں دو بار انہیں اپنی جامعہ میں بلایا‘ تو ہزاروں کی تعداد میں نوجوان تھے۔ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ کپتان نے نئی نسل کو ایک مدت گزرنے کے بعد متحرک کیا‘ فکری طور پہ نہیں‘ فقط سیاسی طور پر کہ انہیں ایک متبادل سیاسی قیادت‘ جماعت اور راستہ نظر آیا۔ دو ہزار آٹھ کے بعد آہستہ آہستہ جذبہ بڑھتا گیا اور جہاں کہیں بھی دیکھا‘ نوجوان عمران خان کا جھنڈا لیے کھڑے تھے۔ لاہور کی کسی جامعہ میں پیش آنے والا وہ واقعہ نہیں بھولے گا کہ ایک کمسن نوجوان بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور پوچھا ”سر بتائیں‘ عمران خان وزیر اعظم کب بنے گا؟‘‘ آخر وہ بن گئے‘ مگر مجھے ڈر ہے کہ وہی نوجوان جب مجھے کہیں ملے گا تو اب یہ ضرور پوچھے گا ”سر! عمران خان کب جا رہا ہے؟‘‘ یہ میں فرض کر رہا ہوں‘ شاید وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہو۔ سچ بات یہ ہے کہ مجھے شک ہے۔
میرے کئی دانشور دوستوں نے کپتان سے امیدیں باندھنا عرصے سے بند کر رکھی ہیں۔ فقیر تو فطری طور پر خوش فہم ہے‘ اس لیے دھوکے میں رہنے کی لت پڑ گئی ہے۔ میرے قریبی دوست میاں محمد شفیع‘ جو بصیرت اور معاملہ فہمی میں بہت آگے ہیں‘ ان کے سامنے کوئی معذرت‘ حکومت کے دفاع کے کام نہیں آ سکتی۔ کہتے ہیں‘ زمین ان کے پیروں تلے سے نکل چکی ہے‘ پنجاب کرپشن اور بدانتظامی کی وجہ سے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ میں بھی قائل سا ہو گیا ہوں کہ حکومت خلا میں تیرتی نظر آ رہی ہے۔ سوچتا ہوں‘ نوجوان ایک مرتبہ پھر مایوس ہو گئے تو شاید مدتیں گزر جائیں کہ وہ کسی سیاسی شخص پہ اعتماد کر سکیں۔







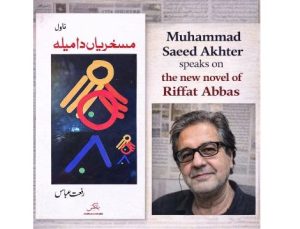


اے وی پڑھو
اُچ ڈھاندی ڈیکھ تے چھوراں وی وٹے مارے ہن۔۔۔|شہزاد عرفان
ریاض ہاشمی دی یاد اچ کٹھ: استاد محمود نظامی دے سرائیکی موومنٹ بارے وچار
خواجہ فرید تے قبضہ گیریں دا حملہ||ڈاکٹر جاوید چانڈیو