
وسعت اللہ خان
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
گزشتہ روز کراچی یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈی سینٹر کے تحت ’’ تاریخ اور جامعات‘‘ کے موضوع پر مورخ ڈاکٹر مبارک علی کی زیرِ صدارت نصف دن کی کانفرنس میں مقالے اور اعلیٰ پائے کی علمی گفتگو سننے اور کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔
مقررین نے بارہا زور دیا کہ علم کے تالے کی کنجی سوال کی چابی سے ہی کھلتی ہے۔ میں نے یہ جملہ مختلف مواقع پر سیکڑوں بار سنا ہو گا۔ لیکن کل پہلی بار یہ بات دماغ سے گولی کی طرح ٹکرائی اور پھر پرتیں کھلتی چلی گئیں۔
مجھے لگا کہ پوری تہذیبِ انسانی سوال پر کھڑی ہے۔ میں کون ہوں؟ تم کون ہو؟ ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟ یہ کیوں چلتی ہے پھر کیوں رک جاتی ہے؟ سورج مشرق سے ہی کیوں نکلتا ہے؟ اگر زمین گھوم رہی ہے تو پھر ساکت کیا ہے؟ جب دماغ کی ساخت ایک طرح کی ہے تو کچھ لوگوں کا دماغ زیادہ کام کیوں کرتا ہے اور کچھ لوگ کیوں اس سے بہت کم کام لے پاتے ہیں۔ کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ جسے ہم پاگل سمجھ رہے ہیں وہی پاگل ہے؟ لوہا اگر پانی سے بھاری ہے تو پھر جہاز کیوں تیرتا پھرتا ہے۔ تہذیب کیسے پیدا ہوتی ہے، عروج پاتی ہے، مر جاتی ہے۔ خیال عقیدہ کیسے بن جاتا ہے اور یہی خیال سائنسی سوچ میں کیسے ڈھل جاتا ہے۔ یہ سوالات کبھی نہ کبھی کسی نے تو اٹھائے ہوں گے تبھی تو ہم غار سے نکل کر خلا کو گھر بنانے میں کامیاب ہو سکے۔
جس طرح خاموشی آوازوں کی مرشد ہے اسی طرح سوال جواب کا باپ ہے۔ سوال کی نوعیت و معیار ہی وہ ڈی این اے ہے جو میرے علمی شجرے کا پتہ دیتا ہے۔ سوال وہ پیمانہ ہے جس سے میری ذہانت، غبابت اور سوچ کی گہرائی یا اتھلا پن فوراً ناپا جا سکتا ہے۔
سوال کا ذہن میں پیدا ہونا فطری عمل ہے لیکن اسے دوسرے کے سامنے رکھنا ایک آرٹ ہے۔ سوال جتنا مختصر ہو گا اتنا ہی موثر اور ٹھوس ہو گا ( لوگوں کی اکثریت سوال کرنا چاہتی ہے مگر ان کی یہ کوشش اپنی ہی لذتِ تقریر کے ہاتھوں شہید ہو جاتی ہے اور طولِ کلام کے جوش میں انھیں خود بھی یاد نہیں رہتا کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں)
کسی بھی سوال کا کوئی مکمل جواب ممکن نہیں۔ بلکہ جواب تو خود وہ پوٹلی ہے جس میں بے شمار سوالات بندھے ہیں۔ جیسے ہی یہ پوٹلی کھلتی ہے گویا بحث کا دروازہ کھل جاتا ہے اور بحث وہ بیضہ دانی ہے جس سے مزید سوالات جنم لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ فوراً مر جاتے ہیں۔ کچھ منطق کی شاہراہ پر جان دے دیتے ہیں اور کچھ اتنے توانا ہوتے ہیں کہ علم کی گاڑی کو اور آگے کھینچتے ہوئے لے جاتے ہیں اور جب تھک جاتے ہیں تو پھر ان کی جگہ نئے اور توانا سوالات علم کی سواری میں جت جاتے ہیں۔ یہی علم ترقی کے زینے طے کرواتا ہے اور یہی علم باؤلا ہو جائے تو پاتال میں اتار دیتا ہے۔
جواب معمولی ہو سکتا ہے مگر سوال معمولی نہیں ہوتا۔ بظاہر یہ سوال کتنا معمولی اور بے وقوفانہ ہے کہ سیب نیچے کی طرف ہی کیوں گرتا ہے اوپر کیوں نہیں جاتا؟ مگر اس ایک سوال نے کششِ ثقل کیسے کام کرتی ہے کا مسئلہ حل کر کے ایک فلکیاتی جہان کھول دیا۔ جب سب انسانوں کے خون کا رنگ ایک سا ہے، دماغ کا حجم یکساں ہے، کرہِ ارض بھی سب کا سانجھا ہے، مرنا بھی سب کو ہے تو پھر یہ اونچ نیچ اور طبقاتی تقسیم کی فارسی کیا ہے؟ اس ایک سوال نے کارل مارکس پیدا کر دیا۔ کیا تشدد بڑی طاقت ہے یا عدم تشدد؟ اس سوال کا جواب گاندھی، مارٹن لوتھر کنگ اور نیلسن منڈیلا کی صورت میں موجود ہے۔
جب انسان کو عقل دی گئی ہے تو پھر اسے ایک تصور یا نظریے کی زنجیر میں میں تاقیامت کیسے جکڑا جا سکتا ہے اور اسے مختلف انداز میں سوچنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے اور جب روکا جاتا ہے تو اس کے کیا فوائد و نقصانات ہوتے ہیں؟ اس ایک سوال نے روشن خیالی کے تصور و تحریک کو جنم دیا۔
سوال پانی کی طرح ہوتا ہے۔ بہتا رہے تو صحت افزا ہے۔ روک دیا جائے تو جوہڑ ہے۔ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ خود کو، آس پاس کو اور جوابات کی تلاش پر نکلے سوالات سے خوفزدہ معاشرے اور پھر اس معاشرے کے خمیر سے اٹھی ریاست کو دیکھ لیں۔ اور پھر ان معاشروں کی کامیابیاں اور ناکامیاں ناپ لیں جنہوں نے سوال کو بیڑیوں سے آزاد کر کے اس سے علم کی توانائی کشید کر کے خود کو ہر شعبے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔
ان سماجوں کو دیکھ لیں جو ’’مستند ہے میرا فرمایا ہوا‘‘ کے گرد کولہو کے بیل کی طرح گھومنے کو سفر سمجھ رہے ہیں اور ان معاشروں کا سفر دیکھ لیں جہاں کی لفظیات میں اس طرح کے جملے روزمرہ کا حصہ بن چکے ہیں کہ ’’ہو سکتا ہے میں غلط ہوں مگر میرا خیال یہ ہے‘‘ ، آپ اگر میرے خیال کو غلط ثابت کر دیں تو مجھے بے حد خوشی ہو گی، اگرچہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا تاہم آپ کے زاویہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اختلاف کے باوجود میں چاہوں گا کہ ہمارا مکالمہ جاری رہے، ممکن ہے ہم کوئی مشترکہ نکتہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔
جس دن ہم اپنی لغت سے بلا شبہہ، یقیناً، بجا فرمایا، در ایں چہ شک، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ، یہ ممکن ہی نہیں ہے، میں ایسی بات ہرگز نہیں سن سکتا، میں یہ پوچھنے کی جرات نہیں کر سکتا، مجھے آپ کے کہے پر کامل اعتماد ہے، بس یہ آخری بات ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطا است جیسی لفظیات و ضرب المثال، محاورات و روزمرہ سے چھٹکارا پانے کی سوچیں گے اور دوسرے کا علم کرائے پر لے کر اپنا علم ثابت کرنے کے بجائے سوال کی سیڑھی پر چڑھ کے تشکیک کے میدان میں کودنے کا ارادہ باندھیں گے اس روز سے ہمارا صدیوں سے رکا ذہنی ارتقائی سفر بحال ہونے لگے گا۔ لیکن اگر آپ نے دوسرے کی بات پوری طرح سنے اور سمجھے بغیر سوال داغ دیا تو ایسا سوال ہٹ دھرمی، کٹ حجتی، مناظرے اور مفت کی کشیدگی کی جانب تو لے جا سکتا ہے علم کے کوچے میں نہیں۔
سوال ایٹم سے زیادہ طاقتور ہے تبھی تو بادشاہ سوال سے ڈرتا ہے، ریاست سوال سے کانپ جاتی ہے۔ آدھا بجٹ ان اقدامات پر صرف ہوتا ہے جو جراتِ سوال کو دبا سکیں۔ کیونکہ سوال دبدبے کو خاک میں ملانے کی صلاحیت رکھتا ہے تبھی تو مدرسے، اسکول، کالج اور جامعہ میں سوال پوچھنے والے طالبِ علم کو بدتمیز، پراگندہ ذہن، گمراہ اور جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، تبھی تو مسئلے کا حل خود تلاش کرنے کی عادت ڈالنے کے بجائے بچوں کو طوطے کی طرح رٹوایا جاتا ہے۔ تا کہ نسل در نسل تابعدار ذہنی غلاموں کی سپلائی میں خلل پیدا نہ ہو اور علم و آگہی کے خزانے پر سانپ بن کر بیٹھے عالموں اور حکمرانوں کا کرو فر برقرار رہے۔ بدتمیز بڑوں سے سوال کرتا ہے؟ کیا والدین نے یہی تربیت دی ہے؟ گستاخ…
پچھلے زمانے میں تو حصولِ علم کے متلاشی کم ذات کے کان میں پگھلا ہوا سیسہ ڈلوا دیا جاتا تھا مگر فی زمانہ یہی کام کانوں میں دہشت انڈیل کے نکالا جا رہا ہے۔
جس اقبال سے اپنے مطلب کے اشعار اور من پسند تشریح چھین کے اسے درسگاہوں اور سرکاری اداروں کی دیوار پر بطور تصویری تبرک ٹانگ دیا گیا ہے اسی اقبال کا یہ بھی تو کہنا ہے۔
چپ رہ نہ سکا حضرتِ یزداں میں بھی اقبال
کرتا کوئی اس بندہِ گستاخ کا منہ بند






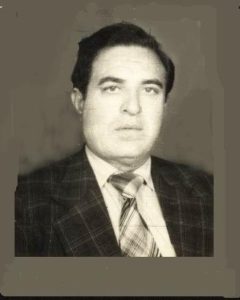



اے وی پڑھو
کریمݨ نقلی۔۔۔||ملک عبداللہ عرفان
دیپک راگ، ثریا ملتانیکر اور لوح اعزاز کی کہانی||رانا محبوب اختر
خالی لفظاں دا میلہ||سعید اختر