
ڈاکٹر طاہرہ کاظمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ہمارا بچپن تو بڑا ہی شاندار تھا جس میں سب ہم عمر بچے ہم سے چڑتے تھے اور شاید ان کی مائیں بھی۔ بڑے ہوئے تب عمر میں کہیں چھوٹے بچوں نے روایت قائم رکھی اور ان کی ماؤں نے بھی۔ سمجھ کبھی نہیں آئی کہ قصور کیا تھا ہمارا؟
قسم لے لیجیے جو ہم مار پیٹ کے عادی ہوں، برا بھلا کہتے ہوں یا ان کی چیزیں چھین کر کھا جاتے ہوں، واللہ کچھ بھی نہیں تھا ایسا مگر پھر بھی کچھ تو تھا جس کے نتیجے میں ہم عمر دور دور رہتے۔
اسکول کے سالانہ امتحان کا نتیجہ جس دن نکلتا اس دن محلے کے ہر گھر میں ہم بصد اصرار بلائے جاتے۔ ان کے امی ابا عینک پہنتے، ہمارا کارڈ دیکھتے اور ہر مضمون کے نمبر دیکھ کر آنکھوں میں سرخی اترتی آتی۔ آخر میں ایک زوردار ہنکارا بھرا جاتا، ’شاباش بیٹی شاباش‘ ۔ پھر دو چار روپے ہمارے ہاتھ پر دھرتے ہوئے ان کی خونخوار نظر اس کونے کا طواف کر رہی ہوتی جہاں ہمارے ہم جولی سر جھکائے بیٹھے ہوتے۔ کھجلی ہوتے ہاتھوں اور شرر بار آنکھوں کو بس ہمارے رخصت ہونے کا انتظار ہوتا۔
یقین کیجیے ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کس کس کو پٹوایا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہم نے پٹوایا؟ ماں باپ ان کے، ڈانٹ پھٹکار ان کے اماں ابا کی، اس سب میں ہمارا کیا لین دین؟ لیکن ہوتا کیا؟ اس عظیم حادثے کے بعد ہم عمر بچے ہمیشہ کے لیے خفا ہو کر ہمارے ساتھ کھیلنا بند کر دیتے۔ نہ بھئی نہ، نہ ان کے ساتھ کھیلیں گے، نہ یہ ساتھ دکھیں گی، نہ ہمارے گھر آئیں گی، نہ اماں ابا ان سے متعارف ہوں گے اور نہ فرمائش کریں گے کہ ذرا بلانا تو اس کو۔
کھیل کود میں شامل نہ کیے جانے کا ہمیں قطعی غم نہ ہوتا کہ ہم کون سا کھلاڑی بننے کو تلے بیٹھے تھے۔ کھیل تو ہمیں ویسے ہی کچھ زیادہ نہیں بھاتا تھا۔ ہم تو کتاب کے ساتھی تھے اور کتاب ہماری۔ سو جب سب منہ پھیر کے ہمارا حقہ پانی بند کر دیتے بلا کسی قصور، اس وقت کتاب آواز دیتی کہ ’آؤ میرے پاس بیٹھو، کچھ میں سناؤں کچھ تم‘ ۔
سوچیے الطاف فاطمہ کا ’دستک نہ دو‘ چوتھی کلاس میں پڑھ لیا کہ آپا بی اے میں تھیں اور کالج کی لائبریری سے کوئی نہ کوئی کتاب لاتی رہتی تھیں۔ گیتی آرا کا کردار، اپنی مرضی کرنے والی اور اپنے باپ کی آنکھ کا تارا۔ ارے یہ کہیں ہم ہی تو نہیں؟
ہیرو صفدر، ہماری زندگی میں تھا تو سہی اسی نام کے ساتھ مگر رول شاید ولن کا تھا۔
خیر ہم سنا رہے تھے محلے کے گھر گھر یاترا کی کہانی۔ کبھی کبھار ششماہی امتحان کے بعد ضرورت پڑ جاتی تھی۔ اگرچہ اس گھر کا بچہ کب سے ہم سے بات کرنا چھوڑ چکا ہوتا تھا مگر پھر بھی لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ ہمیں بلاوہ دیتا، ’چلو امی ابا تمہیں بلا رہے ہیں‘ ۔
اب کوئی پوچھے کہ اہالیان محلہ ہمارا نام اگر نہیں بھولتے تھے تو اس میں ہمارا کیا قصور تھا بھلا۔ مسمسی سی شکل بنا کر ہم ساتھ ہو لیتے۔ دوست کے امی ابا سے ملاقات کا مقصد تو ایک ہی تھا۔ لٹمس ٹیسٹ کا کردار جو ہم سے پوچھے بغیر ہمیں سونپ دیا گیا تھا۔ اس ٹیسٹ کی روشنی میں وہ سب وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کے اسکول کی کارکردگی چیک کر کے مناسب جھاڑ پونچھ کا اہتمام کرتے۔
ہمیں یقین ہے کہ بہت سے دلوں سے نکلی بددعائیں سمیٹی ہوں گی ہم نے۔
بڑے ہوئے تو اگلی نسل متنفر ہو گئی۔ مثال دینے کے لیے ہمارا نام کوئی نہ بھولتا۔ دیکھو دیکھو پھوپھی کی طرف، اس طرح پڑھا جاتا ہے، خالہ سے پوچھو کیسے انعام جیتتے ہیں، باجی سے مقابلہ کرنے کے گر سیکھو۔ بار بار کا قصیدہ سن کر سب بچوں کے منہ میں کونین کا ذائقہ آنے لگتا۔ نہ صرف بچوں کو بلکہ ان کے اماں ابا کو بھی جو ہمیں نہ جانے کیوں رقیب سمجھ بیٹھے تھے۔ خیر ہم کبھی سمجھ ہی نہ سکے کہ ہماری ذات کتنے بچوں کو چبھی بلکہ چبھائی جا رہی ہے۔
ہمارے نزدیک زندگی صرف اول آنے کا نام تھا۔ کم نمبر کیسے آتے ہیں؟ فیل کیسے ہوا جاتا ہے؟ قطار کے آخر میں کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے؟ یہ باب ہماری کتاب میں تھے ہی نہیں۔
لیکن زندگی تو سبق سکھا دیتی ہے بلکہ دماغ درست کیے بنا چین سے نہیں بیٹھتی اور ہمارے ساتھ تو ایسا ہونا ہی تھا کہ ایک دنیا انتظار میں تھی کہ کیسے ہوں گے اس کے بچے؟ کون کون سے ریکارڈ قائم نہ کریں گے وہ؟ اور شاید ہم بھی دل ہی دل میں مان بیٹھے تھے کہ ہمارے بچے، ہاں بھئی ہمارے اور بچے قطار میں چوتھے، پانچویں نمبر پر؟ نہ نہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دن دیکھنے سے پہلے موت کیوں نہ آ جائے ہمیں؟
زندگی میں پہلی بار پٹخنی تب کھائی جب ہماری ننھی بیٹی اسٹیج پر چڑھی اور مائیک دیکھ کر اس کی آواز گلے میں ہی پھنسی رہ گئی۔ ہم جو کیمرہ اٹھائے انتہائی جوش و خروش سے فلم بندی کے لیے تیار کھڑے تھے، اپنے قدموں پر کھڑے بھی نہ رہ سکے کہ ہماری بیٹی اور اسٹیج فوبیا؟ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اسٹیج ہمارے لیے تو وہ میدان تھا جہاں کوئی تقریری مقابلہ ہو یا ذہنی آزمائش کا مقابلہ، فینسی ڈریس شو ہو یا بیت بازی، ٹرافی کسی اور کو ملے، ناممکن۔
ایسی دھواں دار تقریر کرنے والی ماں کی بچی اور گلے سے آواز ہی نہ نکلے، تقریر کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں، یا اللہ۔ کیا بوالعجبی ہے؟
دوسری بیٹی کو اسٹیج پر چڑھایا تو وہ مائیک کے سامنے تقریر کرنا ہی بھول گئی۔ اسپتال سے آدھی چھٹی لے کر ہم بھاگے بھاگے اسکول پہنچے تھے، سر نہوڑائے شرمندہ ہوتے رہے۔ کیسے بے وقوف تھے ہم۔
پھر زندگی نے ایک اور امتحان دکھایا جب ایک ساتھی ڈاکٹر کا بچہ اسٹیج پر چڑھ کر اول انعام لے رہا تھا اور وہیں کہیں کسی کونے میں ہم بھی مرجھائی شکل کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ساتھی ڈاکٹر جو ہمارے ماضی کو جانتی تھیں، انہوں نے اسٹیج پر جاتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں جملہ کسا ’کچھ محنت بچوں پر بھی کر لینی تھی، اپنے بچوں کو بھی اپنی طرح لائق بنایا تھا نا‘ ۔
ایسا لگا کسی نے کلیجے میں تیر دے مارا ہو۔ پھٹی پھٹی نظروں سے ہم ان کی طرف دیکھتے رہے اور ساری حاضر جوابی اڑن چھو ہوئی۔
کچھ ہی دن بعد سانپ سیڑھی کے اس کھیل میں اوندھے منہ جا گرے جب ایک دوست نے مشورہ دیا کہ ہماری بیٹی کے لیے بیوٹی پارلر کا کورس بہتر رہے گا۔ جو بچے ہائی اسکول میں کسی بھی وجہ سے زیادہ نمبر نہ لے سکیں انہیں کوئی ہنر سکھا دینا چاہیے۔ تب بھی دل مسوس کر ہم انہیں دیکھتے رہے۔
پھر فیس بک پر اپنے بچوں کے گریڈز اور سرٹیفیکٹ لگانے کا مقابلہ شروع ہوا۔ یقین کیجیے بچپن کے محلے دار ماں باپ یاد آ گئے جو ہمارا رزلٹ کارڈ منگوایا کرتے تھے۔ گویا زمانہ بدل گیا مگر ذہنیت وہی رہی، یعنی اپنے بچے کو ٹرافی سمجھنے کی عادت۔
جو بات ہمارے اماں ابا کو مختلف بناتی تھی وہ یہ کہ کبھی بھی اپنے کسی بچے کو کسی اور کے ساتھ کسی بھی میزان میں نہیں تولا، یہاں تک کہ اپنے ہی 6 بچوں کا ایک دوسرے سے کوئی تقابل نہیں۔ ہم اول آئے تو بہت خوب، دوسرے 10 ویں، 12 ویں پوزیشن پر آئے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب کا اپنا اپنا نصیب اور زندگی کی دوڑ میں حصہ۔ اماں ابا کی یہی بات انہیں دنیا کے بیشتر ماں باپ سے ممتاز کر گئی۔
وقت کا امتحان آج ثابت کرچکا ہے کہ تعلیمی امتحان، ان میں حاصل کیے جانے والے نمبر اور اس وقت مقابلے کی دوڑ میں کچھ پیچھے رہنے کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی یا بچہ ناکام ہو گیا۔ اس بات کی تائید ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ تعلیم کی پیچیدگیوں اور ان میں نمبروں کے کھیل کو ماسٹرخت یونیورسٹی ہالینڈ سے سیکھا۔
سمجھ لیجیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے گن استعمال نہیں کر پاتا، اپنے آپ کو دریافت کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسے جس راہ پر چلایا جا رہا ہوتا ہے وہ راہ اس کے لیے نہیں بنا ہوتا بلکہ وہ تو کسی اور منزل کا مسافر ہوتا ہے۔ امتیازی نمبر نہ لینے کو ناکامی سے تعبیر کرنے والوں کا ذہن شاید اس جوہڑ کی مانند ہوتا ہے جو تازہ پانی کی خوشبو سمجھ ہی نہیں پاتا۔
ایک بات ہم نے اور بھی سیکھی اور وہ بھی اپنے بچوں سے کہ کوئی بھی بچہ دوسرے کا کلون نہیں ہوتا۔ خالہ، پھوپھی، چچا، ماموں، ان کی اولاد حتیٰ کہ ماں باپ کا بھی۔
’کلون نہیں ہیں ہم آپ کے۔ ماما کے تین ٹکڑے، ہو بہو ایک جیسے، کیوں بھلا؟ ہم ہم ہیں، آپ نہیں‘ ۔ یہ ہے وہ ڈائیلاگ جو ہمارے گھر کی دیواریں اکثر سنتی ہیں اور خوب ہنستی ہیں۔ آخر کسی نے تو اس بڑھیا کو لاجواب کیا۔
سمجھ آ گیا کہ ہر انسان کی پرواز کا اپنا آسمان ہے اور وہ آسمان تب ہی دریافت کیا جاسکتا ہے جب ننھے پرندے کی ہلکی اور آہستہ رو پرواز کو بھی ماں باپ تعریفی نظر سے دیکھیں، ہمت بندھائیں اور اسے وہ افق دریافت کرنے کا خواب دکھائیں جو دور کہیں دور نظر سے اوجھل ہے لیکن ہے ضرور، وہاں تک پہنچنا ناممکن نہیں۔ کیا ہوا اگر رفتار کچھ کم رہی یا وہ بلندی حاصل نہ ہو سکی۔
ہمت اگر نہ ٹوٹے، حوصلہ اگر بڑھایا جاتا رہے، بچے کے سر پر دست شفقت قائم رہے، کندھے پر تھپکی ملتی رہے تو بچہ دنیا میں کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یقین کیجیے ہمیں اس بات پر یقین آ چکا ہے۔
بشکریہ ڈان
یہ بھی پڑھیے
ایک مثالی عورت کیسی ہونی چاہیے
یہ بھی پڑھیے:
اسقاط حمل میں عورت پر کیا گزرتی ہے؟۔۔۔ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی
کاظمی اینڈ سنز عرف سترہ برس کا بیٹا۔۔۔ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی






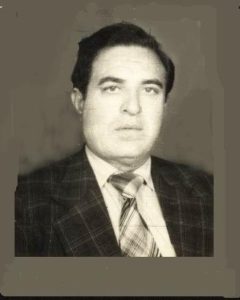



اے وی پڑھو
کریمݨ نقلی۔۔۔||ملک عبداللہ عرفان
دیپک راگ، ثریا ملتانیکر اور لوح اعزاز کی کہانی||رانا محبوب اختر
خالی لفظاں دا میلہ||سعید اختر