 وجاہت مسعود
وجاہت مسعود
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
مولانا ابوالکلام آزاد فروری 1922 میں بغاوت کے الزام میں کلکتہ کی عدالت میں پیش کیے گئے۔ انگریز مجسٹریٹ کے روبرو بیان دیتے ہوئے ایک ایسا تراشیدہ اور ٹھکا ہوا جملہ کہا کہ قول فیصل قرار پایا۔ ’’تاریخ عالم کی سب سے بڑی نا انصافیاں میدان جنگ کے بعد عدالت کے ایوانوں ہی میں ہوئی ہیں۔‘‘ مولانا واقعتاً مرد آزاد تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظلم کا ہزار پا مطلق العنانی کی دلدل میں پلتا ہے اور نا انصافی کا خار پشت رات کے اندھیرے میں پھولوں کی کیاریاں اجاڑ دیتا ہے۔ میدان جنگ اور عدالت کی تخصیص نہیں، حرمت انسانی کی مرمریں دیوی ان گنت زاویوں سے روندی جاتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ تاریخ کی تاریک گپھائوں میں راستہ بنانے والوں کا واحد سرمایہ امید کا مدھم دیا ہوتا ہے۔ اپنے فیض صاحب ہی کو لیجیے۔ 21جولائی 1952 کو ڈاکٹر مصدق کے حامی ایرانی طلبا پر گولی چلی تو پنڈی سازش کیس کے زندانی شاعر نے آواز اٹھائی، ’’یہ کون سخی ہیں… یہ لکھ لٹ، جن کے جسموں کی بھرپور جوانی کا کندن…‘‘لیکن 4 جنوری 1965 کو فیلڈ مارشل کے سپوت گوہر ایوب خان نے فاطمہ جناح کے حامی اہل کراچی کے لہو سے ہولی کھیلی تو ’’بے آسرا یتیم لہو‘‘ کی پکار سن کر ہمارے شاعر کے ہاتھوں سے امید کا چراغ چھوٹ گیا۔’ ’نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا‘‘۔ ہماری تاریخ ایسے ان گنت خونچکاں قصوں سے عبارت ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک سیاسی رہنما نے سرکاری درس گاہوں میں سیاسی جلسے منعقد کیے تو مجھے 24 اپریل 2015 کو بلوچ گمشدگان کے حق میں آواز اٹھانے والی سبین محمود کا قتل یاد آیا جسے بعد ازاں صفورہ گوٹھ کی صف ماتم میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ 13 اگست 2020 کو تربت میں کراچی یونیورسٹی کا طالب علم حیات بلوچ اپنے والدین کی موجودگی میں ریاست کی گولیوں کا نشانہ بنا تو ایک ذمہ دار افسر نے درویش کو بتایا کہ حیات بلوچ زنگ آلود ہینڈ گرینیڈ اٹھاتے ہوئے ہلاک ہوا تھا۔ یہ ایک مسکت جواب تھا۔ 20 جنوری 2021 کو حیات بلوچ کے قتل کے ملزم سپاہی شادی اللہ کو سزائے موت سنائی گئی تو درویش نے ہینڈ گرینیڈ کی حکایت سنانے والے صاحبِ اختیار سے رابطے کی جسارت نہیں کی۔ ایک گمنام شہری کیسے آواز اٹھا سکتا ہے اگر دستور کی محافظ عدلیہ 440 ماورائےعدالت قتل کے واقعات کے ملزم پولیس افسر سے سوال نہیں کرتی کہ عدالت عظمیٰ کے حکم کے باوجود وہ مہینہ بھر کہاں روپوش رہا؟ کراچی کی مجسمہ ساز عدیلہ سلمان کے فن پارے کی تباہی بہرصورت تاریخ کا حصہ بن چکی۔ 21 فروری 1952 کو ڈھاکہ کے ایس پی مسعود محمود کے حکم پر شہید کیے جانے والے بنگالی طالب علموں کی ایک خستہ حال یادگار کھڑی کی گئی تھی۔ 25 مارچ 1971 کی لہو آلود رات یہ یادگار منہدم کر دی گئی۔ اب ڈھاکہ میں اسی مقام پر ایک عظیم الشان یادگار ایستادہ ہے۔ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اگر جنوری 2005 میں ڈاکٹر شازیہ خالد کی پکار پر کان دھرا جاتا تو بلوچستان کی وفاقی اکائی گزشتہ سترہ برس سے سرزمین بے آئین نہ ہوتی۔
گزشتہ ہفتے نشتر میڈیکل ہسپتال ملتان کی چھت سے درجنوں ناقابل شناخت لاشیں برآمد ہونے کی خبر نکلی۔ وزیراعلیٰ کے ایک مشیر نے جائے وقوعہ کا دورہ کر کے الزامات کی تصدیق کی۔ ہسپتال انتظامیہ نے کبھی پولیس پر لاوارث لاشیں لانے کا دوش دھرا تو کبھی میڈیکل کالج کے طلبا کی تدریس میں ان لاشوں کی موجودگی کا جواز تلاش کیا۔ یہ سب وضاحتیں درست ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ شمالی بلوچستان میں لورالائی سے چار سو میل دور ملتان تک کوئی مناسب ہسپتال موجود نہیں چنانچہ مسخ شدہ لاشوں کے بلوچی لباس کی یہ توجیہ ممکن ہے کہ یہ لوگ علاج کے لیے یہاں لائے گئے تھے اگرچہ یہ باور کرنا مشکل ہے کہ پاکستان میں کون سا مریض لواحقین کے بغیر بلوچستان سے ملتان پہنچ سکتا ہے۔ درویش میں یہ اشارہ کرنے کی جرأت نہیں کہ پاکستان میں مبینہ مسنگ پرسنز کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ گیبریل گارشیا مارکیز نے ’تنہائی کے سو برس‘ میں ایک ٹرین کا منظر بیان کیا ہے۔ بہت بعد میں مارکیز نے کہا تھا کہ جس زمین سے قانون اٹھ جائے، وہاں چلتی ہوئی ٹرین میں یونائٹیڈ فروٹ کمپنی کے کیلوں کی کھیپ بھی ارسال کی جا سکتی ہے اور 1928 میں قتل ہونے والے کولمبیا کے 3000 شہریوں کی لاشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ملک میں برسہا برس روزانہ کی بنیاد پر خودکش حملے ہوتے رہے۔ عام طور پر حملہ آور کی لاش کے ٹکڑے ہی ہاتھ آتے تھے مگر نادرا میں موجود بائیو میٹرک نظام کی مدد سے بیشتر حملہ آوروں کی شناخت کر لی جاتی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ملتان کے معروف ترین ہسپتال میں لائی جانے والی لاش بغیر کسی تحقیق کے لاوارث قرار دے کر چھت پر پھینک دی جائے۔ یہ کسی حادثے کا شکار ہونے والے شہری کا لاشہ بھی ہو سکتا ہے، اندھے قتل کی واردات ہو سکتی ہے، گھریلو تشدد کا شاخسانہ ہو سکتا ہے، یہ جسد خاکی کسی خفیہ عقوبت خانے میں جان دینےوالے کا ہو سکتا ہے، پولیس مقابلے میں مارا جانے والا کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی منشیات کا عادی فرد ہو سکتا ہے، کوئی بے گھر شہری ہو سکتا ہے، جسم فروشی کے اڈے پر جھگڑے میں مرنے والا ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ہسپتال کے اہلکاروں یا مقامی پولیس پر الزام دھرنا آسان ہے لیکن بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اس ملک میں شہری نام کی مخلوق زندہ یا مردہ ہر دو حالتوں میں لاوارث ہے۔ سوائے ان برگزیدہ افراد کے جو اشارہ غیبی پا کر اعلیٰ عدالتوں میں آئینی درخواستیں دائر کرتے ہیں۔ انہیں صحافی شہری شاہد اورکزئی یا شہری طاہر بھٹی وغیرہ کا لقب دیتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ جہاں لاوارث لاشیں ملتی ہیں وہاں شہری جرم، حادثے یا سازش کی رسی سے معلق ہو جاتا ہے اور ریاست ’قوم گم گشتہ‘ قرار پاتی ہے۔ ریاست کیلئے یہ اسم صفت برتنے پر درویش کو غدار قرار نہ دیا جائے۔ یہ ترکیب قوم کے بانی رہنمائوں میں سے ایک سردار شوکت حیات کی خود نوشت کا عنوان ہے۔
یہ بھی پڑھیے:
منجھلے بھائی جان کی صحافت۔۔۔ وجاہت مسعود
ایک اور برس بڑھ گیا زیاں کے دفتر میں۔۔۔وجاہت مسعود
وبا کے دنوں میں بحران کی پیش گفتہ افواہ۔۔۔وجاہت مسعود
اِس لاحاصل عہد میں عمریں یونہی ڈھلتی ہیں۔۔۔وجاہت مسعود






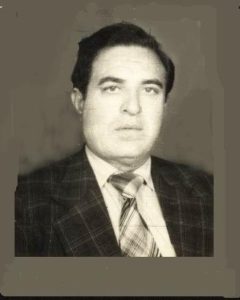



اے وی پڑھو
کریمݨ نقلی۔۔۔||ملک عبداللہ عرفان
دیپک راگ، ثریا ملتانیکر اور لوح اعزاز کی کہانی||رانا محبوب اختر
خالی لفظاں دا میلہ||سعید اختر