
وسعت اللہ خان
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
یہ معلومات اب غیر متعلقہ سی لگتی ہیں کہ ضیا محی الدین کے والد خادم محی الدین چونکہ خود ایک ماہرِ ریاضیات، موسیقی کے پا رکھی، گیت کار و ڈرامہ نگار تھے لہذا صاحبزادے پر اس ماحول و صحبت کا اثر ہونا لازمی تھا یا جب انگریزوں نے پنجاب کو ہندوستان کا اناج گھر بنانے کے لیے یہاں نہری نظام کا جال بچھایا اور ساندل بار اور نیلی بار کے دوآبے میں زمینیں آباد کرنے کی ترغیبات دیں تو رہتک و حصار کے لوگ بھی یہاں آن بسے اور اس نئی نئی زرخیزی کے مرکز لائل پور میں ضیا محی الدین کا بھی جنم ہوا۔
یہ جنم انیس سو انتیس میں ہوا کہ تیس، اکتیس، بتیس، تینتییس میں۔ یہ بھی غیر متعلقہ ہے۔اہم یہ ہے کہ ان کا جنم ہوا۔ وہ زمانہ برصغیر میں آئیڈیل ازم، امنگ اور اٹھان کا دور تھا۔اس ماحول میں اقبال اور جوش تو بن چکے تھے۔ راشد، فیض، علی سردار، کیفی، میرا جی، منٹو، کرشن چندر، بیدی، بلراج ساہنی ، نور جہاں، بیگم اختر وغیرہ وغیرہ زیرِ تعمیر تھے۔ ترقی پسند تحریک اور انقلابیت جوان تھی۔
تھیٹر کے ہیرو بادشاہ اور شہزادے کے منصب سے اتر کے عام آدمی کے عام سے خوابوں کے ڈھابے پر بیٹھنے لگے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی نوٹنکئیت بھی روپ بدل رہی تھی۔
آغا حشر اور رفیع پیر بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل رہے تھے۔زیڈ اے بخاری جیسے لوگ پڑھنت کے لیے تازہ لہجہ بن رہے تھے۔بمبئی اور لاہور کا پارسی تھیٹر سیلولائیڈ میں مدغم ہو رہا تھا اور قدیم ہندوستانی ڈراما جدیدیت کی کوکھ سے دوسرا جنم لینے کے لیے مچل رہا تھا۔
زیادہ موثر تخلیقی و فنی اظہار کے لیے ریڈیو کی شکل میں ایک نیا اور کہیں موثر میڈیم پیدا ہوتے ہی دوڑنے لگا تھا۔اس ایک ڈبے نے آرٹ کے اظہار کو ایک نیا اور وسیع میدان عطا کر دیا اور پھر یہ میدان چند ہی برس میں بھانت بھانت کی تازہ آوازوں اور لہجوں سے بھر گیا۔
غرض کسی بھی نو عمر لڑکے یا لڑکی کے لیے فائن آرٹ اور پرفارمنگ آرٹ کا حصہ بننے کی فضا پہلے سے کہیں سازگار تھی۔ضیا محی الدین بھی اسی تخلیقی خوشے کا ایک دانہ تھا جسے اپنا آپ ابھی منوانا تھا۔
ان کے ساتھ کے کچھ لوگ تخلیقی جنم لیتے ہی مر گئے۔کچھ نے فائن و پرفارمنگ آرٹ کی انگلی پکڑتے پکڑتے فنی لڑک پن تو گزار لیا اور پھر دیدہ و نادیدہ مجبوریوں کے جھکڑ میں کہیں گم ہو گئے۔جو سخت جان نکلے انھوں نے بیسویں صدی کے دوسرے نصف سے خود کو منوا لیا۔
ان میں ضیا محی الدین بھی تھے۔
وہ شاید لڑکپن میں ہی تاڑ گئے تھے کہ انھوں نے آرٹ کی جس طرز سے خود کو بیاہنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی پرداخت و آب داری کے لیے مغرب کا رخ کرنا ہی پڑے گا۔لہذا انھوں نے مزید سوچنے میں وقت گنوانے کے بجائے ایک نادیدہ دنیا میں زقند بھر لی۔فیصلہ پر خطر تھا۔
گمنام اور نام چین ہونے کا امکان آدھوں آدھ تھا۔گویا ایک متوسطی لڑکے کے لیے ہر طرح سے جوا تھا۔
مگر مشکل یہ ہے کہ چیلنج قبول نہ کرو تو کامیابی چھوڑ ناکامی تک ہاتھ نہیں آتی۔ضیا دونوں طرح کے انجام کے لیے ذہنی طور پر آمادہ تھے۔اور پھر انھیں وہی کچھ مل گیا جو چاہتے تھے۔اچھا اسٹیج ، اچھے استاد ، اچھے ساتھی ، اچھی روشنی ، اچھے سامع و ناظر اور سب سے بڑھ کے برموقع مواقع۔اور اس سب نے ہمیں وہ ضیا محی الدین گوندھ کے دیا جو آج تک تھا اور کل تک ہے۔
اور اس ہونے کے پیچھے انگلستان میں سینتالیس برس کے قیام کے دوران شیکسپیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے ، نسل پرست انگلش تھیٹر کی دنیا میں اپنی جگہ بنا کے کسی کو خاطر میں نہ لانے والے گوروں سے خود کو منوانے اور اس منواہٹ کے بل بوتے پر برٹش ٹی وی اور امریکن فلمی دنیا میں اپنی جگہ بنانے اور پھر اس تجربے کو ثوابِ جاریہ میں بدلنے کے لیے پاکستان واپسی اور اب سے پچپن برس پہلے رئیلٹی شوز کے ماڈل سے مقامی ٹی وی کو متعارف کروانے اور روایتی اسٹیج کو جدید سوچ اور تکنیک کا انجکشن لگانے اور پھر اس پورے تام جھام کو آگے بڑھانے کے لیے نئے آرٹسٹوں کی دریافت ، اس خام مال کی تربیت اور انھیں شوبز کے کل کا جزو بنانے سمیت اور کیا کیا ہے جو ضیا محی الدین کے دائرہِ عمل سے باہر رہ گیا ہو۔
زندگی کی آخری تہائی کو ضیا صاحب نے صنعتِ پڑھنت، فنِ داستان گوئی کی آبیاری اور نئے ٹیلنٹ کی کاشت کاری میں گذار دیا۔
میری بالمشافہ یادیں ستمبر دو ہزار بارہ سے دسمبر دو ہزار پندرہ تک کی ہیں۔جب علی الصبح نو بج کے پندرہ منٹ پر ایک کار نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس (ناپا) کے دروازے سے اندر داخل ہوتی تھی اور پورچ میں جا لگتی تھی۔
ایک خوش لباس جوان بوڑھا اس میں سے نمودار ہوتا اور ٹک ٹک کرتا تیر کی طرح کمرے کے دروازے کے پیچھے غائب ہو جاتا۔اوروں کا دن چوبیس گھنٹے کا تھا۔اس خوش لباس کا دن اڑتالیس گھنٹے کا تھا۔
ضیا صاحب کی کلاس دوپہر دو تا تین بجے ہوا کرتی تھی۔شاگردوں کو حکم تھا کہ ایک بج کے پچپن منٹ تک اپنی نشست پر بیٹھ جائیں۔ٹھیک دو بجے ایک ہرکارہ گنتی کے لیے آتا۔پانچ منٹ بعد ضیا صاحب کمرے میں داخل ہوتے اور پھر اس کمرے کی کائنات ان کے اشارے پر ہوتی۔
تین برس اس کلاس میں بیٹھنے کا فائدہ بس اتنا ہوا کہ جس زبان ، تلفظ اور ادائی پر میں گزشتہ چار عشروں سے بزعمِ خود اتراتا تھا۔سارے کس بل نکل گئے۔
معلوم یہ ہوا کہ میری کم ازکم پچاس فیصد اردو اور بولنے کا انداز غلط ہے۔ضیا صاحب نہ ہوتے تو باقی زندگی بھی اعتمادِ جہل کے سہارے خوشی خوشی گذار لیتا۔مگر ضیا صاحب نے مجھ سے یہ فخرِ جہل چھین کے تار تار کر دیا۔( تھینک یو ضیا صاحب )۔
یہ بھی رواج تھا کہ فائنل ایئر کی آخری پرفارمنس کے ہدائیت کار ضیا محی الدین ہی ہوں گے۔اس پلِ صراط سے گذر کے مجھے اندازہ ہوا کہ ڈائریکٹر اچھا ہو تو پتھر سے بھی اداکاری نکلوا سکتا ہے ( سامنے کی مثال ہے میری )
جب فائنل پرفارمنس ہو گئی تو ضیا صاحب نے پہلی اور آخری بار کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا ’’ تم تو لکھتے بھی ہو۔اپنے اس تجربے کے بارے میں بھی کچھ لکھو ‘‘۔ان کے حکم پر میں نے ایک الوداعی مضمون لکھا۔میں نے کیا لکھا قلم نے آبِ دل میں ڈبو کے خود ہی لکھ کے تھما دیا۔اس کی پہلی سطر یہ تھی۔
’’ جب ناپا کے تین سالہ تھیٹر ڈپلوما کورس میں داخلہ لیا تو میری عمر پچاس برس تھی۔آج میں سینتالیس برس کی عمر میں ناپا چھوڑ رہا ہوں ‘‘۔
ضیا صاحب نے کمرے میں بلایا۔دراز سے اپنی کتاب ’’ تھیٹرکس ‘‘ ( تھیٹریات ) نکالی اور دستخط کر کے مجھے دے دی۔
بشکریہ : ایکسپریس
(وسعت اللہ خان کے دیگر کالم اور مضامین پڑھنے کے لیےbbcurdu.com پر کلک کیجیے)
یہ بھی پڑھیں:
قصور خان صاحب کا بھی نہیں۔۔۔وسعت اللہ خان
اس جملے کو اب بخش دیجئے ۔۔۔وسعت اللہ خان
کیا آیندہ کو پھانسی دی جا سکتی ہے ؟۔۔۔وسعت اللہ خان






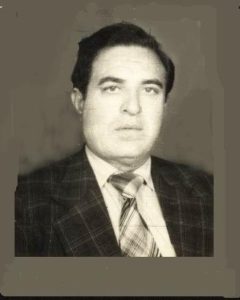



اے وی پڑھو
کریمݨ نقلی۔۔۔||ملک عبداللہ عرفان
دیپک راگ، ثریا ملتانیکر اور لوح اعزاز کی کہانی||رانا محبوب اختر
خالی لفظاں دا میلہ||سعید اختر