
ڈاکٹر طاہرہ کاظمی
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دو ہزار بیس کا آخری سورج ڈھل رہا ہے۔ شام کا ملگجا اندھیرا، درختوں کے لمبے ہوتے سائے، پرندوں کی نیچی اڑان، کچھ کہتا ہوا سناٹا، تھمی ہوئی ہوا، تھکی تھکی لہریں، خاموش سمندر!
پچھلے برس کی آخری شام کسے معلوم تھا کہ ہماری زندگیوں میں کیا طوفان آنے کو پر تول رہا ہے؟ ہم دو ہزار انیس کو جس اطمینان اور خوشی سے الوداع کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ ہی دن میں ہم سے چھننے والا ہے؟ کون سوچ سکتا تھا کہ ہم نے زندگی کی جو ترتیب دو ہزار بیس کے لئے طے کر رکھی ہے وہ تلپٹ ہونے جا رہی ہے؟ کسے اندازہ تھا کہ جو زندگی دھیمے سروں اور اپنے بہاؤ میں ہمیں سمیٹے ہوئے ہے وہ بہاؤ طوفان بننے کو ہے؟ کسے علم تھا کہ بہت سوں کی امیدیں، آرزویں، خواب اور تعبیریں، سب چکناچور ہونے کو ہیں؟
کون جانتا تھا کہ اندھادھند بھاگتی دوڑتی، پر لگائے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنے والی، آہستہ رو کو کچل کے گزر جانے والی اور کسی کو خاطر میں نہ لانے والی زندگی ٹھہر جانے پہ مجبور ہونے کو ہے؟
ایک ننھا جرثومہ زمین پہ ٹڈی دل کی مانند حملہ کرنے کو ہے جو ہر نفس کی اصل عیاں کر دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔
مشکل کی گھڑی میں کون کس کا ہاتھ پکڑتا ہے؟ کون معاشرے میں اپنی ذمہ داری پہ پورا اترتا ہے؟ کس کی آنکھ دوسرے کے لئے نم ہوتی ہے؟ کون زندگی اور موت کے اس کھیل میں احساس کی دولت بانٹ سکتا ہے؟ یہ سب عیاں ہو چکا، اندھوں کے شہر میں بینائی کی پہچان ہو چکی۔
جنوری کے خنک دن تھے جب چین سے عجیب وغریب خبروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ماضی میں کچھ اور ایسے ہی وائرسسز سے پالا پڑ چکا تھا اور ان سے نمٹا بھی جا چکا تھا سو یہی خیال ہوا کہ یہ بھی گزر جائے گا۔ بیرون ملک سے چھٹیوں پہ گھر آئے بچے واپس لوٹے تو کسی کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ بیچ میں جدائی اور وسوسوں کا سمندر حائل ہونے کو ہے۔
دوسرے مہینے میں ان خبروں کا سلسلہ اٹلی کی طرف سے آنا شروع ہوا جہاں وائرس تشویشناک حد تک پھیل کے موت کا کھیل کھیل رہا تھا۔ ابھی تک یہی خیال تھا کہ یہ محض اتفاق ہے کہ چین سے جنم لینے والا وائرس اٹلی تک اتنی تیزی سے پھیلا اور ہلاکت پھیلا دی۔ لیکن پھر موت کا یہ کھیل ایران اور امریکہ تک بھی پہنچ گیا اور ایران سے فضائی رابطے اسی مہینے میں منقطع ہوئے۔
ہمیں ابھی تک حالات کی سنگینی کا احساس نہیں تھا۔ دوست و احباب سے ملنا جلنا، گپ شپ کی محفلیں اور لذت کام و دہن کے دعوت نامے کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔
مارچ اپنے ساتھ بہار کی نوید تو لایا لیکن اب کی بار بہار پہ خوف کے سائے منڈلا رہے تھے۔ فضا میں دبی دبی سی بے چینی اور ہراس کا احساس ہونے لگا تھا۔
خوف کی گھنٹی تب بجی جب ہمیں ہسپتال سے چھٹی منسوخ ہونے کا حکم نامہ ملا، اور وسط مارچ میں دنیا بھر نے اپنے بارڈرز بند کرنے شروع کر دیئے۔ ہماری بڑی صاحبزادی اپنے مطالعاتی دورے پہ سپین کے کسی دور دراز علاقے میں تھیں جب ایک صبح ہمیں گھبرائی ہوئی آواز میں فون آیا، اماں کل سے امریکہ کا بارڈر بند ہو رہا ہے، کیا کروں؟ کیسے پہنچوں واپس؟
حواس پہ قابو رکھتے ہوئے کچھ دن بعد کی شڈیولڈ فلائٹ کو بھلاتے ہوئے اسے فوراً کوئی بھی ٹکٹ کسی بھی قیمت پہ لینے کی اور واپس میڈرڈ جلد ازجلد پہنچنے کی ہدایت کی جہاں سے نیویارک کی فلائٹ پکڑی جا سکے۔ وہ کچھ گھنٹے قیامت بن کے گزرے۔ جی مسلسل ہول رہا تھا کہ خدا کرے دیار غیر میں بچی کسی ابتلا کا شکار ہوئے بغیر اپنے گھر پہنچ جائے۔ نیویارک لینڈ کرنے اور بارڈر بند ہونے میں بال برابر ہی وقفہ رہا۔
ابھی اس اذیت سے نکلے نہیں تھے کہ چھوٹی صاحبزادی کی یونیورسٹی بند ہونے اور ہوسٹل چھوڑنے کا حکم آ گیا۔ فوراً ان کی اگلے ہی دن واپسی کی سیٹ بک کروائی لیکن صبح کے اخبارات پھر سے ہماری بے بسی پہ زہر خنداں تھے۔ عمان کے بارڈرز بند ہونے کا اعلان تھا اور بیٹی کی فلائٹ کچھ گھنٹے بعد پہنچنا تھی۔ نتیجتاً ان کو جہاز پہ سوار ہونے سے ہی روک دیا گیا۔ بڑی بیٹی کوارنٹین میں تھی اور چھوٹی کا نیویارک جیسے ابتلا زدہ علاقے میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا بھی ناممکن تھا۔ پریشانی کے اس عالم میں ہمارے مہربانوں اسد اور سائرہ نے ہماری بیٹی کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور اپنے بچوں کی طرح چاہا۔ ہم عمر بھر ان کی محبتوں کے قرضدار رہیں گے۔
کرونا عمان پہنچ چکا تھا۔ ہسپتالوں میں نئے قواعد نافذ ہو چکے تھے۔ زندگی ماسک اور حفاظتی شیلڈ کے پیچھے رک رک کے سانس لیتی تھی۔
ہم محاذ جنگ پہ اگلی صفوں کے سپاہی تھے اور مکار دشمن سے مقابلہ تھا۔ لیکن کیا کہیے کہ دشمن آنکھ سے اوجھل تھا۔ کس رخ سے حملہ کر کے زیر کرے گا، یہ کسی کو علم نہیں تھا۔ کون اپنی سانس اور اپنے لمس میں دشمن کو پال رہا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔
آپریشن ٹیبل پہ لیٹا ہوا مریض، زچگی کے عمل سے گزرتی کراہتی ہوئی عورت، اسقاط کے درد سے تڑپتی خاتون، حمل کی پیچیدگیوں کی شکار مریض، مریضوں کے لواحقین، ساتھی ڈاکٹر اور نرسیں، خاکروب، چوکیدار، کلرک، سیکرٹری، گراسری سٹور کے سیلزمین، ارد گرد چلتے لوگ! کس کی آستین میں کیا پوشیدہ ہے، کسی کو خبر نہیں تھی۔
صبح گھر سے نکلنے سے پہلے یہی خیال آتا تھا، شاید آج ہماری باری ہو۔ ہم سب ایک دوسرے کو خوفزدہ نظروں سے تکتے تھے۔ سب کی ہنسی اور باتیں لبوں پہ آنے سے پہلے ہی دم توڑ جاتی تھیں۔ کسی مریض کو دیکھنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ پیشہ ورانہ ذمہ داری تھی۔
کام اور ذہنی ہیجان بہت بڑھ چکا تھا۔ ہم ایسی جنگ کے سپاہی تھے جن کو اپنے دفاع کے لئے صرف ماسک ہی کا سہارا لینا تھا۔ ساتھ میں یہ فکر بھی لاحق کہ کہیں ہمارے ذریعے یہ موذی گھر کے مکینوں تک نہ پہنچ جائے۔
ہسپتال میں پہننے والے ملبوسات کی دھلائی کے مختلف طریقے وضع کیے گئے۔ ہر بار باہر سے آنے پہ غسل لازم ٹھہرا۔ خوردونوش کی اشیا کو بلیچ والے پانی میں ڈبکی دلوائی جاتی رہی۔ ہر فرد خانہ کو ہم سے بات کرنے کے لئے ماسک پہننے کی پابندی کرنی پڑی۔
یوں تو بے شمار کرونا کے مریض بے خبری میں دیکھے گئے کہ کووڈ کا نتیجہ بعد میں سامنے آیا لیکن ایسا بھی ہوا کہ ہمیں کووڈ پازیٹو مریضوں کے آپریشن کرنے پڑے۔ کئی دفعہ ٹیم لیڈر ہونے کی حثیت سے دوسروں کو بچا کے خود آگے بڑھنا پڑا۔
ایسے ہی ایک موقع پہ کوووڈ پازیٹو مریض کا سیزیرین ہماری ایک ایسی ساتھی کو کرنا تھا جو ذیابیطس کی مریضہ تو تھیں ہی لیکن ان کو زمانہ قریب میں ہارٹ اٹیک کے بعد سٹنٹس بھی ڈالے گئے تھے۔ ان کی شکل پہ بے تحاشا خوف، آزردگی اور بے بسی دیکھ کے ہم سے رہا نہ گیا۔ بےخطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔۔۔ ہم نے اس سیزیرین کی حامی بھری اور انہیں آپریشن تھیٹر سے باہر بھیج دیا۔
خاص لباس پہن کے یونہی خیال آیا کہ من موہنی صورتوں والے دو جگر کے ٹکڑے تو سات سمندر پار بستے ہیں۔ کیا ممکن ہو گی ان چاند چہروں کی پھر سے دید؟ دل میں ایک ہوک سی اٹھی، لیکن فرض تو نبھانا ہی تھا۔ اس آپریشن میں تینوں بچے جنہیں ہم نے بطن سے یکے بعد دیگرے برآمد کیا اور وہ ہمارے ہاتھوں میں گلا پھاڑ پھاڑ کے روئے، تینوں کے تینوں کرونا پازیٹو نکلے۔
سو اس دن ہم نے چار افراد کی وائرس بھری سانس کی فضا میں وقت گزارا۔ گھر آکے یونہی بچوں سے ذکر کیا تو تینوں کی آنکھوں میں موتی چمکنے لگے۔ اماں، آپ ٹھیک رہی گی نا؟ حیدر نے چپکے سے پوچھا۔ ہاں میرے بیٍٹے، تم لوگوں کی محبت مجھے اس جنگ میں فاتح قرار دے گی۔
شہر بند ہو چکا تھا اور لوگ اپنے گھروں میں مقید تھے۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ تنہائی تھی۔ بات کرنے کو زباں ترستی تھی۔ ہسپتال میں ہم سب نے چپ سادھ لی تھی۔ روبوٹس کی طرح کام کرتے ہوۓ سب سوال و جواب دم توڑ چکے تھے۔
ہسپتال سے واپسی پہ آ کر ہم باہر لان میں بیٹھ جاتے۔ نیلاہٹ بھرا آسمان ساتھی ہوتا، درختوں کے سائے اپنی آغوش میں لے لیتے، پرندوں کی چہچہاہٹ گیت بن جاتی، گرم پروا ہمیں سہلاتی، پھولوں کے رنگ اور سبزا اعصاب کو سکون دیتا۔ برگد کی پھیلی ہوئی جٹائیں ہمیں سہارا دیتیں۔ تنہائی، مایوسی اور کام کے بوجھ میں یہی سب ہمارے ساتھی تھے۔
دن پہ دن گزرتے گئے اور ہم پہ زندگی کے راز منکشف ہوتے چلے گئے۔ کئی ہیرے سی چمکتی چیزیں پیتل نکلیں اور کئی خواب سراب۔ زندگی میں اہم اور غیر اہم کا فرق واضح ہوتا چلا گیا۔ زندگی کی اندھادھند بھاگ دوڑ کی بے معنویت کھل گئی۔ طاقت و اختیار معمولی وائرس کے سامنے سر بسجود ہوئے۔
اسی دوران ہمارے کچھ ساتھی وائرس کا شکار ہوئے۔ ایک جاں بہ لب حاملہ خاتون کو بچانے کی خاطر ہماری دوست ڈاکٹر عائشہ نے کسی بات کو خاطر میں لائے بغیر اس مریضہ کا دل پھر سے رواں کرنے کے لئے سی پی آر کیا۔ مریضہ تو جانبر نہ ہو سکی لیکن ڈاکٹر عائشہ کی باری آ چکی تھی۔ وہ پندرہ دن جو انہوں نے اکیلے کمرے میں تنگ ہوتی سانسوں کے ساتھ تڑپتے گزارے اور ان کے دو ننھے منے بچے بند دروازے کے پیچھے سے انہیں پکارا کرتے، وہ کسی کی بھی آنکھیں نم کرنے کے لئے کافی تھا۔
ہمارے مصری ساتھی انیستھٹسٹ جن
کا گزشتہ بارہ برس سے یہ معمول تھا کہ وہ مریض کو بے ہوش اور ہم آپریشن کرتے اور بعد میں چائے کے کپ پہ ہم دونوں اپنی اپنی بیٹیوں کی تعلیمی کامیابیوں کا ذکر کرتے۔ ہر آپریشن ڈے پہ پوچھتے ، آپ اتنے ملکوں میں جا چکی ہیں، مصر کیوں نہیں آتیں؟ چلیے، آپ شرف میزبانی مجھے بخش دیجیے۔
ایسے ہی ایک آپریشن میں ڈاکٹر ابواوض شکار ہوئے، کچھ روز میں سانسیں اکھڑیں، وینٹی لیٹر پہ گئے اور پھر یہ جنگ ہار گئے۔ پردیس کی مٹی نصیب ہوئی اور دور دیس میں رہنے والی بیٹیاں باپ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکیں۔
ہماری کلاس فیلو ڈاکٹر تقدیس کے شوہر اسلام آباد میں شکار ہوئے اور جانبر نہ ہو سکے۔
اس عالمی ابتلا کے شکار تو سب ہی بنے، سب کی زندگی مایوسی اور مضمحل پن کا شکار ہوئی، سب ہی آس و نراس کے جھولے میں جھولتے رہے لیکن باقی سب میں اور ہم ڈاکٹرز میں ایک فرق تھا۔ ہم دشمن کے حضور روزانہ حاضری دیتے، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھتے اور پھر اس خیال کے ساتھ گھر واپس آتے کہ شاید آج…. یا شاید کل…
اس آج اور کل کے کھیل اور امید وبیم کے تنے ہوئے رسے نے جس اضطراب، بے کلی، مایوسی، چڑچڑے پن اور اداسی میں مبتلا کیا اس میں بے اختیار اور بے حساب دل چاہا کہ مہربان دوست و احباب ہماری کیفیات کو سمجھیں، محسوس کریں اور اپنا تسلی بھرا ہاتھ، اپنا وقت اور اپنی ہمدردی کے دو بول ہماری نذر کریں کہ اس وقت برستی گولہ باری میں مورچوں میں دبکے بیٹھے ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس دفاعی ہتھیار تو ہیں نہیں لیکن پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہتے۔
کیا کہیے کہ ہماری اس ان کہی کو کچھ صاحب دل نے سمجھا اور جانا اور کچھ کے پاس شاید سمجھنے کو وقت نہیں تھا یا احساس کی دولت میں کچھ کمی تھی۔ ابتلا میں شاید ایسی ہی آپادھاپی ہوا کرتی ہے۔
ان اداس شاموں اور تلخ دنوں نے جس نے ہمارا بھرپور ساتھ دے کے ہمارا حوصلہ بڑھائے رکھا، ہمارا یقین متزلزل نہیں ہونے دیا، وہ ہمارا قلم تھا۔ ہمارے اضطراب اور بے چینیوں کا ساتھی قلم، جس کے گواہ آپ سب بنے۔
کہنے اور سنانے کو بہت کچھ ہے۔ کہاں تک کہیں کہ اس برس کا لہو آشام رنگ تو دامن دل سے چھٹنے والا نہیں۔
سورج غروب تو ہو رہا ہے لیکن جاتے جاتے اس نوید کے ساتھ کہ موذی کا توڑ ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ ویکسین کی ذرہ بکتر پہنائے جانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ بیس سو اکیس میں امید واثق ہے کہ اپنے پیاروں کے درمیان حائل فاصلوں کا سد باب ہو گا اور جدائی کی اداس دن کٹ جائیں گے۔
چلتے چلتے دو ہزار بیس کا شکریہ کہ ہمارے پاس ابھی بھی زندگی کی دولت موجود ہے اور وہ سب جو ہم نے اس برس میں سیکھا۔ وہ احساس جو ہم بھلا چکے تھے کہ انسان بحثیت انسان کس قدر اہم ہے، کسی پہچان اور کسی لاحقے کے بنا!
کیا ہی عجیب برس تھا!
تڑپ بھی تھی اور سسکیاں بھی
جدائی بھی اور ساتھ بھی
کہیں چپ تھی اور کہیں ڈوبتے الفاظ کی گونج
تیز ہوائیں سرسراتی تھیں
سمندر خاموش تھا
چاند اداس تھا
چراغوں کی لو تھرتھراتی تھی
دور کہیں صبح کاذب کا اجالا
ایک نئی سحر کی نوید
ٹوٹے ہوئے شیشوں کی مسیحائی
ایک آس
چلو پھر سے بنتے ہیں
کچھ خواب
نیا برس آنے کو ہے






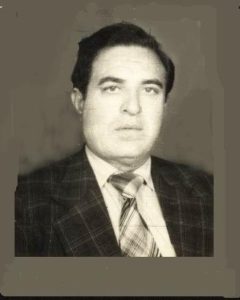



اے وی پڑھو
کریمݨ نقلی۔۔۔||ملک عبداللہ عرفان
دیپک راگ، ثریا ملتانیکر اور لوح اعزاز کی کہانی||رانا محبوب اختر
خالی لفظاں دا میلہ||سعید اختر